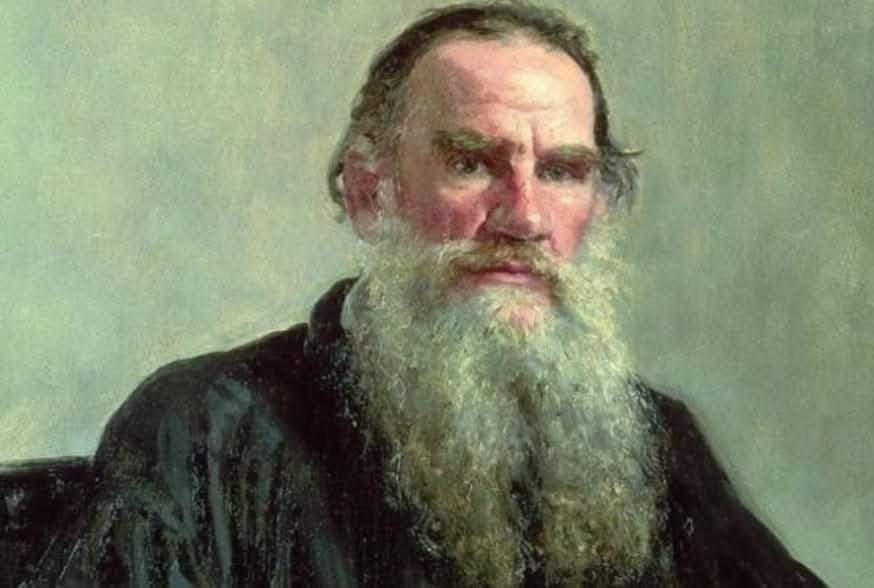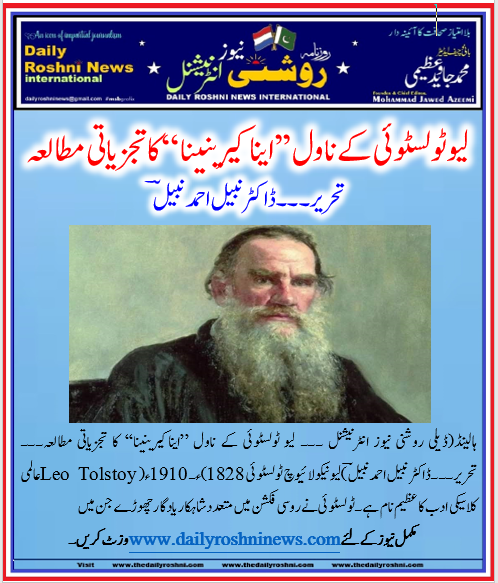
ہالینڈ(ڈیلی روشنی نیوز انٹرنیشنل ۔۔۔ لیو ٹولسٹوئی کے ناول ’’ایناکیرینینا‘‘ کا تجزیاتی مطالعہ۔۔۔ تحریر۔۔۔ڈاکٹر نبیل احمد نبیلؔ)لیونیکولائیوچ ٹولسٹوئی1828)ء۔1910ء (Leo Tolstoyعالمی کلاسیکی ادب کا عظیم نام ہے۔ٹولسٹوئی نے روسی فکشن میں متعدد شاہکار یاد گار چھوڑے جن میں
War and Peace ،Albert،Anna Karenina، Boyhood ،Father Sergius،Master and Man ،Resurrection،The Cossacks،The Forged Coupon،The Kreutzer Sonata، Youth ,A Confession ,The Death of Ivan Ilych شامل ہیں۔ ٹولسٹوئی کے فکشن میں Short Stories کی بھی ایک طویل فہرست ہے مگر ٹولسٹوئی کے دو ناول اُس کے شاہکار Master Piece)) ہیں ‘ایک’’War and Peace‘‘ اور دوسرا ’’Anna Karenina‘‘ اینا کیرینینا(Anna Karenina) 1872-77ء کے درمیان کے منظرنامے کو Depictکرتا ہے۔ اس ناول کا انگریزی زبان میں ترجمہ 1901ء میں Constance Black Garnettنے کیا۔ اس ناول کا اردو میں ترجمہ 1966ء میں انعام الحق نے کیا جو دارالاشاعت ماسکوسے شایع ہوا۔ آننا کارینینا جو انیسویں صدی سے لے کر آج تک ناول کے قارئین کا خاص طور سے اور ادب میں دلچسپی لینے والوں کا عام طور سے محبوب ترین ناول ہے۔ اس کی مقبولیت کا ایک حوالہ یہ بھی ہے کہ اس پر ہالی وڈ نے ایک فلم بھی بنائی جو Box Officeپر بے حد مقبول ہوئی۔
اس ناول کا محرک ٹولسٹوئی کی بیوی کی ڈائری میں لکھا ہوا وہ واقعہ ہے جو ’’یاسنکی ریلوے اسٹیشن پر پیش آیا جہاں آننا سٹپا نوونا نامی ایک عورت نے اپنے محبوب کی بے وفائی کے ردِ عمل میں ٹرین کے نیچے آ کر خودکشی کر لی۔‘‘ (1) اس واقعہ کو بنیاد بنا کر ٹولسٹوئی نے اپنے تخیل کے تانے بانے سے ایک پس منظر تیار کیا۔ ٹولسٹوئی کو ایک ایسے مرکزی خیال کی تلاش تھی جس کے گرد گھومتے ہوئے کرداروں کے ذریعے وہ اپنے معاشرے کے زخموں پر سے پَٹی کھول سکے اور دکھا سکے کہ اس کا معاشرہ کن زخموں سے چُورچُور ہے اور کون سی معاشرتی،روحانی اور اخلاقی بیماریاں معاشرے کو گھن کی طرح کھائے جا رہی ہیں۔ اس سلسلے میں اس نے اپنے ایک دوست N.N. Strakhow کو جو خط لکھا ہے وہ اس بات کی گواہی بھی دیتا ہے۔ (1)
“If I wanted to say in words everything that I had it in mind to express in the novel I should have to write the very novel that I have written all over again.”(2)
(ترجمہ : اگر میں الفاظ میں ہر چیز کے بارے میں کہنا چاہوں جو کہ ناول میں اظہار کے لیے میرے دماغ میں تھاتو مجھے یہ ناول نئے سرے سے ایک بار پھر لکھنا پڑتا۔)
اس ناول میں ٹولسٹوئی نے سات نمایاں کردار تخلیق کیے ہیں، جو یہ ہیں :
(i) اینا کیریینیا (ii) اس کا شوہر الکسئی الکساندروچ (iii) آننا کا بھائی ہے ابلونسکی (iv) اس کی بیوی کِٹی (Kitty) (v) بھاوج ڈولی(Dolly) جو سٹیوا ابلونسی (Stiva Oblonsky)کی بھاوج ہے (vi) آننا کا محبوب ورونسکی(Vronsky) (vii) لیون (Levin)۔ مندرجہ بالا کرداروں میں سے اینا کیرینینا، اس کا شوہرالکسئی الکساندروچ، آننا کا بھائی ابلونسکی یہ تو ایک کنبے کے چار افراد ہیں۔ اس کے علاوہ پانچواں کردار اینا کیرینیناکا محبوب ورونسکی، انھی میں دو کردار جو کہ لیون اور اُس کی بیوی کے ہیں یہ آخری دو کردارہیں۔ یہ ناول کے ضمنی کردارہیں مگر ناول میں بہت مضبوط اور دوسرے کرداروں پر اثرانداز ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیون ایک جاگیردار ہے جو اس دور کے جبر کی علامت بھی ہے۔ اس کردار کے ذریعے ٹولسٹوئی نے اس دور کے کسانوں پر ہونے والے جبر، اس جبر سے جنم لینے والے مسائل اور ان کا حل بھی دکھانے کی سعی کی ہے، لیکن جاگیردار لیون کے مذہبی اور انقلابی نظریات میں ہمیں ٹولسٹوئی کے اپنے ذہن کی تصویر نظر آتی ہے۔
ناول کی کہانی کچھ اس طرح ہے کہ اس ناول کی ہیروئن آننا جو شادی شدہ ہے اور ایک بچے کی ماں ہے۔ ایک نوجوان ورونسکی سے محبت میں مبتلاہو جاتی ہے۔ اسے محبت کہا جائے یاشیفتگی( Infatuation) ۔ یہ سوال قاری کے ذہن میں ضرور اُبھرتا ہے کہ جس کا جواب اسے ناول کے مطالعے سے مل بھی جاتا ہے۔ ایک شادی شدہ عورت اپنے شوہر کے علاوہ کسی دوسرے کے عشق میں مبتلا ہوتی ہے تو اس کا سبب جنسی ناآسودگی بھی ہو سکتا ہے اور یہ بات آننا کے کردار سے واضح ہوتی ہے چوں کہ وہ ورونسکی سے جسمانی تعلق بھی قائم کرتی ہے اور یہ بات ڈھکی چھپی نہیں رہتی، سب کو معلوم ہو جاتی ہے۔ اس طرح اس کی عصمت ہی نہیں، اس کی شہرت بھی داغ دار ہو جاتی ہے۔ ورونسکی ، کوآننا کے ساتھ کچھ دُور چل کر اس بات کا احساس ہوتاہے کہ اگر وہ ایک دوسرے میں کھو گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ معاشرہ ان سے برگشتہ ہو جائے اور وہ تنہا رہ جائیں۔ وہ سوچتا ہے کہ معاشرے سے بغاوت اپنی جگہ لیکن قطع تعلقی سے زندگی جس طرح جہنم بن گئی ہے اس میں اس کا زندہ رہنا مشکل ہو گا۔
ورونسکی نے اپنے رویے سے آننا کو ان باتوں کا احساس نہ ہونے دینے کی کوشش کی، لیکن اس میں اسے کامیابی نہیں ہوئی، اس لیے کہ آنناکاریینیا ایک حسّاس اور ذہین عورت تھی۔ اس نے جو راستہ اختیار کیا یعنی شوہر کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے کے ساتھ شوہر جیسے تعلق استوارکر لیے تھے۔ اس کی بنا پر معاشرہ تو اسے پہلے ہی دُھتکار چکا تھا۔ اب اسے یہ خوف کھائے جا رہا تھا کہ اس کا محبوب ورونسکی بھی اسے معاشرے کے دبائو میں آ کر چھوڑ نہ دے۔ یہ خوف اس کے اعصاب پر اس طرح غالب آ گیا اوروہ اس بوجھ تلے اس قدر دب گئی کہ اس نے ٹرین کے نیچے آ کر خودکشی کر لی۔
ناول کے آغاز میں آننا کے بھائی اور بھاوج کو اس بات پر جھگڑتے ہوئے دکھایا گیا ہے کہ اس کا بھائی اس کی بھاوج کے ہوتے ہوئے کسی اور عورت میں دل چسپی لے رہاتھا جو اس کے بھائی کی ازدواجی زندگی کے لیے زہر قاتل تھی۔ آننا اس جھگڑے میں ثالث کا کردار ادا کرتے ہوئے دکھائی گئی ہے مگر بعد میں وہ خود اسی گناہ کا شکار ہو جاتی ہے۔ اس صورتِ حال کو اپنے ناول کا موضوع بنا کر ٹولسٹوئی نے درحقیقت انسان کی فطرت میں رچی بسی گناہ کی جبلت کو دکھانے کی کوشش کی ہے جس سے بڑے بڑے پارسا بھی اپنا دامن نہیں بچا پاتے۔ انسان کے کردار کی یہ کمزوری اسے پستی کی آخری حد تک بھی لے جانے سے گریز نہیں کرتی۔
عجیب بات ہے کہ معاشرہ ان لوگوں کو تو قصوروار نہیں ٹھہراتا جو مذکورہ نوعیت کے درپردہ گناہ میں ملوث ہوتے ہیں اور دوسروں کو اس کی خبر نہیںہونے دیتے۔ آننا سے یہ گناہ معاشرے کی اقدار سے بغاوت کر کے سرزد ہوا جس پر معاشرے نے اس کا بائی کاٹ کر دیا۔ اس کی ماں نے بھی اسے بہت کچھ بُرا بھلا کہا ۔ حال آں کہ اس کی ماں بھی جوانی میں ایسی ہی تھی۔ خود اس دور کے معاشرے میں اعلیٰ طبقے کی خواتین میں شادی کے بعد ڈھکے چھپے معاشقے عام تھے، لہٰذا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آننا کواس معاشرے نے گناہ کی نہیںبلکہ اعترافِ گناہ کی سزا دی کیوں کہ آننا نے اپنے اس معاشرے پر بظاہر پردہ ڈالنے کی کوشش نہیں کی۔ اس کا شوہر الکسئی الکساندروچ کا کردار معاشرے میں ان سرکاری ملازمین کے رویے اور سائیکی کی نمایندگی کرتا ہے جو اعلیٰ سرکاری عہدے پر کام کرتے کرتے محض ایک مشین کے پُرزے کی مانند بن جاتے ہیں۔
ٹولسٹوئی نے اینا کیرینینا کے شوہر کی اس کے منصب کی ذمہ داریوں کے حوالے سے جو تصویر کشی کی ہے اس سے اس دور کے زارِ روس کے طرزِ حکومت اور انتظامی طریقوں کی تصویر سی بن جاتی ہے۔ جس میں کھو کر کوئی بھی شخص گھریلو مسائل کی جانب زیادہ توجہ نہیں دے سکتا۔ جب اسے اپنی بیوی کے معاشقے کا علم ہوتا ہے تو وہ اسے غلط راستے پر جانے سے روکتا ہے، لیکن وہ راستہ نہیں بدلتی۔ ٹولسٹوئی نے الیکساندروچ کے اس معاملے کے ذریعے اس کی سوچ ناول کے قارئین تک پہنچائی ہے۔ الیکساندروچ اپنی بیوی آننا سے کہتا ہے:
’’ایک وقت تھا جب میں نے اندرونی رشتوں کی بات کی تھی۔ اب میں ان کا ذکر نہیں کرتا۔ اب میں ظاہری رشتوں کی بات کرتا ہوں۔ آپ نے بدسلیقگی برتی اور میں نہیں چاہتا کہ دوبارہ ایسا ہو۔‘‘ ۳؎
آننا پر اس کا بھی کوئی اثر نہیں ہوتا اور وہ اس سے علیحدگی چاہتی ہے مگر وہ شوہر الکساندروچ کی معاشرے میں بدنامی کے خوف سے اسے طلاق نہیں دیتا، لیکن وقت آگے بڑھتا رہتاہے اور آننا اپنے محبوب ورونسکی کی ناجائز بچی کی پیدایش پر اپنے شوہر کے لیے بدنامی کا مزید باعث بن جاتی ہے تو بھی الکساندروچ اس خوف سے لوگوں کوجب پتا چلے گا کہ اس کی بیوی کسی اور کے بچے کی ماں بن گئی ہے تو لوگ اس پر (الکساندروچ) پر ہنسیں گے اور اسے تضحیک کا نشانہ بنائیں گے۔ الکساندروچ اس بچی کو اپنا نام دے دیتا ہے اور آننا کی موت کے بعد بھی اسے اپنے پاس ہی رکھتا ہے۔
ٹولسٹوئی نے الکساندروچ کے کردارکے ذریعے معاشرے کے ان لوگوں کی تصویر پیش کی ہے جو اپنے سرکاری فرائض کی بجا آوری میںاپنی ذات سے متعلق جو معیارات وضع کرتے ہیںان پر خوف کے سائے منڈلاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ معاشرے کی نام نہاد اقدار سے مغلوب ہو کر ظاہر داری کو اپنا معمول بنا لیتے ہیں۔
ٹولسٹوئی نے ناول کی ہیروئن کے کردار کو اس کی باریک ترین جزئیات کے ساتھ تحریر کیا ہے جس کی وجہ سے وہ ایک کتابی عورت نہیں بلکہ گوشت پوست کی ایک حقیقی عورت نظر آتی ہے۔ ٹولسٹوئی نے آننا کو جوایک معزز خاتون تھی فرشتے کے روپ میں پیش نہیں کیا۔ اس میں بشری کمزوریوں کی گنجایش کا اعتراف کیا ہے۔ وہ اپنے معزز خاندانی حالات کی بلندیوں سے جذبات کے ریلے میں بہتی ہوئی جب اخلاقی پستی کی طرف لڑھک رہی ہوتی ہے تو اس صورتِ حال کے لمحے لمحے کی کیفیات اور اس کی ذہنی کشمکش کو الفاظ کے پیکر میں اس طرح ڈھالا ہے کہ ہم آننا کو ایک جیتی جاگتی عورت کے روپ میں دیکھنے اور محسوس کرنے لگتے ہیں۔
آنناکاریینیا ایک نارمل بیوی سے جب اپنے محبوب کی بانہوں میں رقص کرتے ہوئے لمحات گزارتی ہے تواسے اپنے محبوب کے جسم سے رغبت پیدا ہونے لگتی ہے جسے وہ بھلانے کی کوشش کرتی ہے لیکن یہ کوشش ذہنی کشمکش کا روپ دھار لیتی ہے اور وہ خود پر قابو پانے کی کوشش کرتی ہے۔ ایک بار ایسا ہوتا ہے کہ ٹرین میں سفر کے دوران میں جب وہ پیٹرز برگ سے واپس آ رہی ہوتی ہے تو وقت گزارنے کے لیے ایک ناول کا مطالعہ کر رہی ہوتی ہے۔ اسی ناول کا ہیرو اس کے لاشعور پر ورونسکی بن کر چھا جاتا ہے اور اس طرح وہ اس راستے پر لاشعوری طور پر قدم بڑھانے لگتی ہے جس پر جانے سے وہ اب تک اپنے آپ کو روکتی رہی ہے۔ ٹرین سے اُتر کر جب وہ اپنے گھر آتی ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ اس کا شوہر حسن اور کشش کے معیار سے بہت نیچا ہے پھر جب وہ ورونسکی سے جسمانی تعلق قائم کر لیتی ہے تو اسے اپنے کردار کی پستی کا احساس ہوتا ہے، اس احساس کو ٹولسٹوئی نے برہنہ روح کا نام دے کر اس کی تصویر کشی ان الفاظ میں کی ہے :
’’اپنے روحانی ننگے پن کے سامنے شرم نے انھیںکچل کر رکھ دیا اور اس پر بھی اثر ڈالا، لیکن اس سارے بھیانک پن کے باوجود جو قاتل اپنے مقتول کی لاش کے سامنے محسوس کرتا ہے، ضروری ہوتا ہے کہ اس لاش کے ٹکڑے کر کے اسے چھپا دیاجائے اور جو کچھ قاتل نے مقتول سے چھین لیا ہے اسے استعمال کیا جائے۔‘‘ ۴؎
ورونسکی (Vronsky)سے جسمانی تعلقات کی بات معاشرے کی آنکھوںسے چھپی نہیں رہ پاتی، بات دوستوںاور عزیزوں سے ہوتی ہوئی آننا کے شوہر تک پہنچتی ہے تو آننا کو احساس ہوتا ہے کہ بات بگڑ گئی ہے اور معاشرہ تو اسے بُرا بھلا کہہ ہی رہا ہے، اس کی اگر وہ پروا نہ بھی کرے تو اپنے شوہر سے کس طرح آنکھیں ملائے گی۔ یہ اس کا احساس تھا جس میں لمحہ لمحہ خوف شامل ہوتا جا رہاتھا۔ اس کے شوہر نے اس کی ناجائز بچی کو اپنا کہہ کر معاشرے کا منہ بند کرنا چاہا، لیکن آننا احساسِ جرم کے گڑھے میں دھنستی ہی چلی گئی اور اس کا خوف اسے اپنی زندگی کے خاتمے پر مجبور کرنے لگا۔ آننا کی اسی ذہنی کیفیت کو ٹولسٹوئی نے بڑی مہارت سے حوالۂ قلم کیا ہے۔خاص طور سے ان لمحات کی تصویر کشی تو بہت ہی ماہرانہ ہے جب آننا خودکشی کے ارادے سے گھوڑاگاڑی میں بیٹھ کر ریلوے اسٹیشن کی طرف جا رہی ہوتی ہے۔ ٹولسٹوئی نے آننا کے دماغ میں چلنے والی شعور کی رو (Stream of Consciousness) کو بڑی خوب صورتی سے پیش کیا ہے۔
’’ان لوگوں نے کیسے مجھے دیکھا جیسے کسی بھیانک، ناقابلِ فہم اور قابلِ تجسس چیز کو دیکھتے ہیں۔ یہ آدمی دوسرے کو اتنے جوش و خروش کے ساتھ کس چیز کے بارے میں بتا سکتاہے؟ انھوں نے دو راہ گیروں کو دیکھ کر سوچا۔ کیا واقعی آدمی جو محسوس کرتاہے، وہ دوسرے کو بیان بھی کر سکتا ہے؟میں ڈولی (Dolly)کوبتانا چاہتی تھی اور اچھا ہی ہوا کہ میں نے کچھ نہیں بتایا اب یہ ہیں تو ان کو یہ گندی آئس کریم چاہیے۔ اس بات کو تو یہ لوگ یقینی طور پر جانتے ہیں انھوں نے دو لڑکوں کو دیکھ کر سوچا جو ایک آئس کریم والے کے پاس کھڑے تھے جس نے سرسے اپنی ہودی اتار لی تھی اور اپنے پسینے سے تر چہرے کو تولیے کے سروں سے پونچھ رہاتھا۔ میٹھی چیز مزے دار چیز ہم سبھی چاہتے ہیں۔ ٹافی نہیں تو گندی آئس کریم ہی سہی اور ایسے ہی کِٹی (Kitty) بھی۔ ورونسکی(Vronsky) نہیں تو لیون (Levin)ہی سہی اور وہ مجھ پر رشک کرتی ہے… بقا کے لیے جدوجہد اور نفرت، بس یہی چیزیں جو لوگوں کو وابستہ رکھتی ہیں۔ نہیں، آپ لوگ بے کار ہی جا رہے ہیں۔ خیال ہی خیال میں انھوں نے چار گھوڑوں کی بگھی میں جاتے ہوئے لوگوں کی ایک ٹولی سے کہا جو بظاہر شہر سے باہر تفریح کرنے جا رہے تھے… اپنے آپ کہیں نہیں جاسکتے۔‘‘ ۵؎
ورونسکی سے جسمانی تعلقات کی بات معاشرے کی آنکھوں سے چھپی نہیں رہ پاتی۔ ٹولسٹوئی نے آننا کے شعور کی رو کو جس طرح لفظوں کا روپ دیا ہے۔ اس کا تقابل اگر جیمز جوائس کی تحریروں سے کیا جائے تو ٹولسٹوئی اس سے بہت بلند نظر آتا ہے۔ ٹولسٹوئی کی اس خوبی کو Vladimir Nabokov نے بھی سراہا ہے۔
“In Tolstoy the device is still in its rudimentary form with the author giving some assistance to the reader but in James Joyce the thing will be carried to an extreme stage of objective record.” ۶؎
(ترجمہ :۔ ٹولسٹوئی نے جو اسلوب اختیار کیا وہ ابھی اپنی ابتدائی حالت میں ہے جس کے ذریعے مصنف اپنے قاری کو سہولت بہم پہنچاتا ہے، لیکن جمیزجوائس کے ہاں یہی چیز معروضی ریکارڈ کی آخری حدتک جاپہنچتی ہے۔)
ٹولسٹوئی کے اُسلوبِ تحریر کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ وہ آنے والے واقعات کی طرف پہلے سے لطیف سا اشارہ دینا ضروری سمجھتا ہے تاکہ قاری جب اسی واقعہ تک پہنچے تو اس کے ذہن میں کوئی ابہام، اُلجھن یا اجنبیت نہ رہے۔ اس کی مثال اس واقعہ سے دی جا سکتی ہے کہ آننا جب پہلی بار ماسکو کے ریلوے اسٹیشن پر آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ ایک آدمی اپنی بے احتیاطی سے ٹرین کے نیچے آ کر ہلاک ہو گیا ہے۔ اسے دیکھ کر آننا کہتی ہے ’’اوہو یہ بُرا شگون ہے۔‘ ‘ ۷؎ آگے چل کر آننا خود بھی ایسے ہی حادثے سے دوچار ہو جاتی ہے یعنی وہ اپنے ضمیر کی آواز پرلبیک کہتے ہوئے ٹرین کے سامنے آ کر خودکشی کر لیتی ہے تو پڑھنے والے کے ذہن میں اسی واقعہ کا فلیش بیک ہوتا ہے جب ماسکو کے ریلوے اسٹیشن پر ایک شخص ٹرین سے کچل کر ہلاک ہو گیا تھا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ وہ بے خبری کی موت تھی جب کہ آننا کو خبر تھی کہ وہ جو کچھ کرنے جا رہی ہے اس کا نتیجہ بھی موت ہے۔ اس واقعہ سے اس دور کے معاشرے کے اعتقادات کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ مذہبی سماج ہو یا غیر مذہبی سماج اس میں اخلاقیات کا ضرور عمل دخل ہوتا ہے اور جب کسی کو اپنے گناہوں کا احساس شدت کے ساتھ ہونے لگتا ہے تو وہ اس گناہوں کے احساس سے چھٹکارا پانے کے لیے اور اپنے ضمیر کی تسکین وطمانیت کے لیے خودکشی میں پناہ تلاش کرتا ہے۔ آننا کارینینا نے بھی ایسا ہی کیا اس نے گناہوں کے عوض موت کو گلے سے لگالیا۔ اس طرح گناہوں کا بوجھ موت کی صورت منتج ہوا۔ انسانی تاریخ میں بہت سے معاشروں میں گناہوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے بعض انسانوں نے خودکشی کا راستہ اختیار کیا۔ ٹولسٹوئی کے عہد میں یہ عنصر عقیدے کی صورت میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس کی ایک مثال اینا کیرینینا کا کردار ہے۔
ٹولسٹوئی اپنے دور کے کسانوں اور مزدوروں پر ہونے والے جبر اور سختیوں کو اپنے دل میں اس طرح محسوس کرتاتھا جیسے یہ سب اس کی ذات پر بیت رہا ہے۔ وہ زندگی بھر ان مظلوموں کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے کوششیں کرتا رہا جس کا عکس اس کے ناولوں اور کہانیوں میں واضح طورپر نمایاں نظر آتا ہے۔ اسی طرح اس کے اسلوب کی انفرادیت بھی قائم ہوتی ہے۔ لینن نے ٹولسٹوئی کے بارے میں کچھ اسی قسم کے خیالات کا اظہار کیا ہے۔
اور کیا آپ جانتے ہیں کہ اس میں حیرت انگیز بات کیا ہے؟ اس سے پہلے کسی نے ادب میں حقیقی کسان کو پیش نہیں کیا۔ ٹولسٹوئی نے جاگیردار لیون کی سوچ کے ذریعے اس دور کے کسانوںکے مسائل اور جاگیرداروں کے ظلم کا پردہ چاک کیا۔ غربت بھی کسانوں کا ایک مسئلہ ہے لیون کسانوں کی غربت کے خاتمے کی سوچ رکھتا ہے کسان جب مال دار ہوگا تو پھر وہ دل جمعی سے کام کرسکے گا۔ جاگیردار، کسانوں کو مساوی حصہ نہیں دیتے تھے۔ ٹولسٹوئی نے لیون کے کردار کے ذریعے اس سوچ اور رویے کو ناپسندیدہ قرار دیا ہے۔ لیون کا Point of View یہ ہے کہ روسی کسان کو اس کی مخصوص جبلت کی روشنی میں دیکھنا چاہیے۔ کسان کے مسائل اور خصوصیات کو سمجھے بغیر روس زراعت کے میدان میں خاطر خواہ ترقی نہیں کرسکتا، لہٰذا جاگیردار کو کسان کے مسائل کو سمجھنا ہوگا۔ کسان کے لیے غربت بہت بڑا مسئلہ ہے اس کی معیشت مضبوط ہوگی تو وہ ذوق شوق سے کام کرے گا زرعی ترقی میں اپنا کردار ادا کرے گا۔ اس نے جاگیردار کے استحصالی رویے اور منفی فکر کو Condemn کرتے ہوئے لیون کے کردار کے ذریعے کسان کے ایشوز کو اجاگر کیا ہے۔: ’’ہم اپنے محنت کشوں کی خصوصیات کو، ان کی عادتوں کو سمجھنا نہیں چاہتے۔۔۔ وہ اپنی رائے پر مصر تھا کہ روسی کسان نہ صرف سو رہے، بلکہ اپنے سورپن پر نہایت نازاں اور خوش بھی ہے۔ روسی کسان کو اس سورپن سے نکالنے کے لیے اقتدار اور طاقت کی ضرورت ہے، جو ہے نہیں، اس کام کے لیے ڈنڈے کی ضرورت ہے، لیکن ہم اس درجہ روشن خیال ہوگئے ہیں کہ ہم نے ہزاروں ہزار سال سے آزمائے ہوئے قدیم ڈنڈے کو پھینک دیا ہے اور اس کی جگہ اچانک وکیلوں اور جیل خانوں پر تکیہ کرنے لگے ہیں۔ جہاں ناکارہ، بدکار اور شری کسان مفت میں بیٹھے بیٹھے روٹیاں توڑتے ہیں، کھانے کو بڑھیا سوپ ملتا ہے، اور سانس لینے کو کئی کئی مربع فٹ تازہ ہوا مہیا کی جاتی ہے۔ ‘’آپ ایسا کیوں سوچتے ہیں، لیون نے گفتگو کا رخ پھراسی بنیادی سوال کی طرف موڑنے کی کوشش کرتے ہوئے پوچھا کہ ہم محنت کشوں کی طرف ایسا رویہ اپنا ہی نہیں سکتے، جس کی مدد سے پیداواری صلاحیت میں اضافہ ممکن ہو۔ ‘’روسی کسانوں کے سلسلے میں تو کبھی ایسی نوبت آہی نہیں سکتی۔ نہ اقتدار ہے نہ ڈنڈا ہے! جاگیردار نے کہا‘۔۔۔ کسان غریب ہے، ان پڑھ ہے، یہ بات تو ہم بھی اس طرح، گویا، جوتے کے تلے میں دیکھ سکتے ہیں، جس طرح دیہاتن ماں سایہ دیکھ سکتی ہے۔ کیوںکہ اس کا بچہ مسلسل چیخ رہا ہے، لیکن اس کی مصیبت میں، غریب اور جہالت میں، یہ اسکول کس طرح اس کی مدد کریں گے۔۔۔ یہ بات اسی حد تک ناقابل فہم ہے جس حد تک یہ بات ناقابل قبول ہے کہ مرغیاں چیخوں کا علاج کرسکتی ہیں۔ علاج تو اسی چیز کا کیجیے جس کی وجہ سے وہ غربت کا شکار ہے۔۔۔ البتہ معمر جاگیرداروں کی باتوں، اور اس کے اخذ کردہ نتائج میں سے کچھ باتیں اور نتائج ایسے تھے، جن پر سنجیدگی سے غور کرنا ممکن تھا۔ لیون کو جاگیردار، کی ایک ایک بات یادآرہی تھی اور پھر وہ خود اپنے جواب یاد کرنے کی کوشش کرنے لگا۔
’ہوں! ان سے کہنا چاہیے تھا: آپ کہتے ہیں کہ ہماری زراعت ترقی نہیں کرسکتی، کیوںکہ کسان کو ہر اصلاح سے نفرت ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ یہ اصلاحات اقتدار اور زور زبردستی کی مدد سے کی جائیں۔ بھئی اگر اس سدھار، ان اصلاحات کے بغیر زراعت قطعی بیٹھ جاتی، تب تو موصوف کی بات درست ہوتی، لیکن زراعت تو بہرحال آگے بڑھتی رہی ہے، جہاں مزدور اور کسان اپنے پرانے ریت رواج کے مطابق کاشتکاری کرتے آئے ہیں۔ جیسے اس بوڑھے کسان کے ہاں، جس سے نصف سفر کے بعد ملاقات ہوئی تھی۔ زراعت سے ہماری اور آپ کی بے اطمینانی اس بات کا ثبوت ہے کہ قصور ہمارا ہے یا کسانوں کا ہے۔ ہم اپنے روسی مزدور کسان کی خصوصیات کو قطعی نظرانداز کرکے زبردستی اپنے یعنی یورپ کے طریقے سے کام کروانے کی کوشش کررہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ محنت کی قوت کو محض ایک مثالی محنت کی قوت کی طرح دیکھنے کے بجائے اسے روسی کسان او راس کی مخصوص جبلت کی روشنی میں کیوں نہ دیکھیں، اپنی کاشتکاری کو اس کے مطابق ترقی کیوں نہ دیں؟ مجھے ان سے کہنا چاہیے تھا کہ ’’ذرا سوچیے، اگر ہم اس لائن پر کاشتکاری کریں جس پر وہ کسان کرتا ہے، کوئی ایسا طریقہ تلاش کرسکیں جس کے تحت ہمارے کسانوں کو دل چسپی پیدا ہوسکے۔۔۔ کام ہیں، اور کام کو آگے بڑھانے میں۔۔۔ اور اگر ہم ایجادات کے سلسلے میں کوئی ایسی غیر معمولی درمیانی راہ تلاش کرسکیں جسے کسان بھی منظور کرسکے تو۔۔۔ اگر ہم یہ سب کرلیتے ہیں تو زمین کی پیداوار فی ہیکٹر دوگنا، بلکہ تین گنا ہوجائے گی، اور وہ بھی زمین کی طاقت کو کھوئے بغیر۔۔۔ آدھاآدھا تقسیم کرلیجیے۔ نصف مزدور اور کسان کو دیجیے، نصف آپ رکھیے۔ آپ کا یہ نصف حصہ بہرحال پہلے کے مقابلے میں زیادہ ہوگا، اور محنت کشوں کو بھی زیادہ مل سکے گا۔ اس منزل کو پانے کی خاطر ہمیں کاشتکاری کا اپنا معیار کم کرنا پڑے گا، اور کھیت کی کل پیداوار میں کسان کی دل چسپی کو جگانا ہوگا۔ یہ کام کیسے کیاجائے۔۔۔ یہ توخیر تفصیلات کا سوال ہے، لیکن اس بارے میں کوئی شبہہ نہیں ہوسکتا کہ یہ ممکن ہے، اور ضرور ممکن ہے۔ ‘‘ (۸)
ایسا محسوس ہوتا ہے کہ لیون کی سوچ میں ٹولسٹوئی کی اپنی سوچ بھی یک جا ہو گئی ہے۔ لیون کے کردار میں ہم ٹولسٹوئی کی اپنی سوچ کو کارفرما دیکھتے ہیں کہ اس دور کا نظام کسان کااستحصال کرنے کے لیے بنا تھا جسے جاگیردار اپنی عیاشیوں میں مزید اضافے کے لیے مضبوط تر کرتے چلے جا رہے تھے۔ لیون کی طرح وہ سمجھتا تھا کہ زراعت کا کلیدی عنصر کسان اور اس کی محنت ہے نہ زمین، ہل، موسم اور کھاد وغیرہ۔ لیون بظاہر ایک جاگیردار ہے، لیکن اس کے اندر ایک مصلح اور کسانوںکا درد آشنا فرشتہ موجود ہے جوکسانوں کے حالاتِ کار کو بہتر بناناچاہتا ہے۔ اس کے لیے وہ عملی کام بھی کرتاہے۔ وہ کسانوں کے ساتھ فصلوںکی کٹائی میں بھی شامل ہوتا ہے اور جسمانی محنت بھی کرتا ہے۔ اس کے دو فائدے اسے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کے ماتحت کام کرنے والے کسانوںاور مزدوروںکی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور وہ زیادہ تندہی سے کام کرتے ہیں، دوسرے یہ کہ اسے احساس ہوتا ہے کہ جو لوگ جسمانی محنت سے گریز کرتے ہیں اور آرام و عیاشی میں اپنا وقت گزارتے ہیں ان کی صحت اچھی نہیں رہتی۔ اسی لیے وہ میڈیکل ڈکشنری میں ایک نئی اصطلاح شامل کرنے کی خواہش کا اظہار کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کام وہ دوا ہے جس سے آرام پسندی اور کاہلی سے پیداہونے والی بیماریوںکا علاج کیا جا سکتا ہے۔ دراصل لیون جو کچھ سوچتا ہے اور جو کچھ کہتا ہے، وہ ٹولسٹوئی کا اپنا زاویۂ نظر ہے جسے اپنے معاشرے کے اشرافیہ کی سہل پسندی اور عیش کی زندگی اچھی نہیں لگتی۔ اس کے مقابلے میں وہ محنتی کسانوں کے معمول اور صحت بخش معمولاتِ زندگی کی تعریف کرتا ہے اور ایک جگہ لیون سے یہ بات کہلواتا ہے۔
’’ہم گائوں میں کوشش کرتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں کو ایسی حالت میں رکھیں کہ کام کرنے میں آسانی ہو۔ اس کے لیے ہم ناخن کاٹ دیتے ہیں اور کبھی کبھی آستین بھی چڑھا لیتے ہیں اور یہاںلوگ ناخن بڑھا لیتے ہیں جہاں تک بڑھ سکیں اور آستینوں کو طشتریوں جیسے بٹنوںسے بند کر لیتے ہیں تاکہ ہاتھوں سے کچھ کام کیا ہی نہ جا سکے۔‘‘ (۹)
ٹولسٹوئی نے اشرافیہ کی فضول خرچیوں اور دولت کی غیر منصفانہ تقسیم کو بھی ہدفِ تنقید بنایا ہے اور اس پس منظر میں لیون کے خیالات اس طرح بیان کیے ہیں۔
’’لیکن جب سوروبل کااگلا نوٹ اس نے رشتہ داروں کی ایک دعوت کے لیے سامان خریدنے کے واسطے بھنایا جو اٹھائیس روبل کا تھا تو لیون کو یہ خیال تو ہوا کہ اٹھائیس روبل کے معنی ہوتے ہیں دس کوارٹ جئی، جو کاٹی جاتی تھی۔ گٹھوں میں باندھی جاتی تھی، گاہی جاتی تھی، اوسائی جاتی تھی، چھانی جاتی تھی اور بوروں میں بھری جاتی تھی اور صاف کرنے میں لوگ تھکتے تھے اور پسینہ بہاتے تھے، پھر بھی یہ اگلا نوٹ خرچ کرنا آسان ترتھا۔‘‘ (۱۰)
لیون کا کردار ٹولسٹوئی نے بڑے مؤثر انداز میں پیش کیا ہے۔ دراصل اپنے معاشرے کی ناہمواریوں کے خلاف جو کچھ بھی ٹولسٹوئی سوچتا ہے اور کسانوں کو اس کا فائدہ پہنچانا چاہتا ہے وہ سب کچھ اس نے لیون کے کردار کے سانچے میں ڈھال دیا ہے۔ لیون مخلص ہے، وہ کسانوں کو جاگیرداروں کے استحصال سے بچانا چاہتا ہے اور جب وہ یہ بات کسانوں سے کہتا ہے تو کسان اس کی بات پر اعتبار نہیں کرتے۔ اس لیے کہ لیون خود بھی تو جاگیردار ہے بلکہ کسان تواس کی نیت پرشبُہہ کرتے ہیں کہ وہ ہمدردی کے نام پر استحصال کرنا چاہتاہے۔ لیون کے کردار کا دوسرا رُخ اس کا باطن ہے جو اس کے ظاہر کی طرح تسلسل کے ساتھ کسی بہتری کی تلاش میں ہے۔ اس کا مسئلہ تلاشِ حق ہے۔ بدقسمتی سے وہ ایسے معاشرے میں زندہ ہے جہاں کسان طبقہ جاگیرداروں کے ہر عمل کو شبہے کی نظر سے دیکھتا ہے جس کا ذکر وہ پادری سے بھی کرتا ہے، لیکن اس کا حل نہ تو اسے فلسفیوں کی کتابوں میںمل پاتا ہے اور نہ خالقِ کائنات کی عبادت میںنظر آتا ہے۔ لیون اپنے داخل کی تمام تر کشمکش کو ان الفاظ میں بیان کرتاہے۔
’’کیا میں عقل سے اس نتیجے تک پہنچا تھا کہ مجھے اپنے پڑوسی سے محبت کرنی چاہیے اور اس کا گلا نہ گھونٹنا چاہیے؟ مجھے بچپن میں یہ بتایا گیا اور میں نے خوشی سے اس پر یقین کر لیا، اس لیے کہ مجھے وہی بتایا گیا تھا جو میرے دل میں پہلے سے موجود تھااور اسے دریافت کس نے کیا؟ عقل نے نہیں۔ عقل نے تو بقا کے لیے جدوجہد اور قوانین دریافت کیے جن کا تقاضا ہے کہ میری خواہشوں کی تکمیل و تشفی میں جتنے لوگ بھی مخل ہوں، ان سب کا گلا گھونٹ دو۔ یہ ہے عقل کا اخذ کردہ نتیجہ اور دوسرے سے محبت کرنے کی دریافت عقل نہیں کر سکتی تھی۔اس لیے کہ یہ بے عقلی ہے۔‘‘ (۱۱)
یہاں پہنچ کر لیون پر وسیع النظری اور کشادہ قلبی کے در وا ہو جاتے ہیں۔ وہ نیکی، بھائی چارے اور محبت کی تبلیغ مسیحیت کے ایک محدود دائرے میں رہ کر کرنے کی بجائے عام انسانوں کے بارے میں سوچتا ہے۔
’’اسے یاد آیا کہ جس چیز کواس نے آنکھ سے اوجھل کر دیا ہے وہ کیا تھی۔ وہ یہ بات تھی کہ اگر الوہیت کا خاص ثبوت اس شے کا انکشاف ہے کہ نیکی کیا ہے تو یہ انکشاف کیوں صرف عیسائیت تک محدود ہے؟اس انکشاف سے بودھوں اور مسلمانوں کا کیا تعلق ہے؟ وہ بھی تو نیکی کی تلقین کرتے ہیں اور نیکی کرتے ہیں۔ اسے لگا کہ اس کے پاس اس سوال کا جواب ہے، لیکن وہ خود اپنے لیے بھی اس کا اظہار نہ کر سکا تھا۔‘‘ (۱۲)
جیسا کہ پہلے بھی لکھا جا چکا ہے کہ لیون کے کردار میں ٹولسٹوئی خود موجود ہے جہاں ٹولسٹوئی اپنا Point of View لیون کے حوالے سے بیان نہیں کر پاتا وہاں وہ اشرافیہ میں ہونے والی بحث و تمحیص کا سہارا لیتا ہے اور اس طرح مختلف موضوعات پر ٹولسٹوئی اپنی سوچ کا اظہار کرتا ہے۔ مثال کے طورپر وہ کلاسیکی علوم کو سائنسی علوم پر ترجیح دینے کا جواز اس طرح دیتا ہے۔
’’مجھے لگتا ہے کہ اس بات کا اعتراف نہ کرنا ناممکن ہے کہ زبانوں کی قواعدو تشکیل و ساخت کا علم حاصل کرنے کا عمل ہی روحانی ارتقا پر خاص طور پر مفید اور خوش گوار اثر ڈالتا ہے۔ اس کے علاوہ اس بات سے انکار کرنا بھی ناممکن ہے کہ کلاسیکی ادیبوں کااثر بہت ہی اعلیٰ درجے کا اخلاقی اثر ہوتا ہے جب کہ بدقسمتی سے نیچری سائنسوں کی تعلیم کے ساتھ وہ نقصان دہ اور جھوٹی تعلیمات وابستہ ہیں جو ہمارے عہد کے ناسورکی حیثیت رکھتے ہیں۔‘‘ (۱۳)
ایک اور جگہ ایک ناول کے ایک معمولی کردار کی گفتگو کی وساطت سے وہ اپنے معاشرے کی آزاد خیالی کو جو اس کے خیال میں موزوں نہیںہے۔ اس طرح ہدفِ تنقیدبناتا ہے۔
’’پہلے یہ ہوتاتھا کہ آزاد خیال وہ شخص ہوتا تھا جو مذہب، قانون، اخلاق کے نظریوں میںتربیت پاتا تھا اورخود جدوجہد اور کدوکاوش کر کے آزاد خیالی تک پہنچتا تھا، لیکن اب ایک نئی قسم نمودار ہونے لگی ہے جو اپنے آپ پنپنے والے آزاد خیالوںکی ہے جو اُگ آتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں، لیکن انھوں نے کبھی یہ سُنا تک نہیں ہوتا کہ قوانین تھے، اخلاق تھے کہ مسلم الثبوت اساتذہ تھے۔ یہاں لوگ براہِ راست ہر چیز سے انکار کر دینے کے نظریے میںپروان چڑھتے ہیں یعنی وحشی ہوتے ہیں۔‘‘(۱۴)
ناول میں جو کہانی بیان کی گئی ہے، اس کا زمانہ فروری ۱۸۷۲ء سے لے کر جولائی ۱۸۷۶ء تک کے تقریباً ساڑھے چار برسوں پر محیط ہے۔ اس زمانے کے منظرنامے میں ماسکو، پیٹرز برگ کے ساتھ کچھ چھوٹے شہر اور دیہات کا ذکر بھی موجود ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ٹولسٹوئی نے اپنے عہد کی دیہی اور شہری زندگی کے مابین تقابل کچھ اس طرح کیا ہے کہ جس سے اس کے اپنے نظریات نمایاں ہوتے ہیں۔ اس بات کی وضاحت Henry Gifford نے اس طرح کی ہے :
“The ideal of the family is honoured by the Shcherbatskys and by Levin whose old home represents for him a whole world, the world that had been the life and death of his parents. It is the world of Mascow tradition, rather than of Petersburg novelty, and these two cities are here, as elsewhere in Russian Literature, used to symbolize the conflict between old pieties and modern pressures. (15).
(ترجمہ :۔ Scherbatskys اور لیون (Levin) خاندان کی مثالیت کو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ لیون (Levin) جس کا پرانا گھر اس کے لیے ایک مکمل دنیا ہے جہاں اس کے والدین نے اپنی موت وحیات کا سفر طے کیا۔ یہ ماسکو کی روایتی دنیا ہے نہ کہ پیٹرزبرگ کی جدت طرازی، اور یہ دونوں شہر یہاں قدیم اقدار وجدید دبائو کے تصادم کی علامت کے طور پر پائے جاتے ہیں، جیسا کہ روسی ادب میں اکثر مقامات پر یہی علامت نگاری دیکھنے کو ملتی ہے۔ )
ٹولسٹوئی کو ناول نگاری کے فن پر دسترس حاصل ہے اور وہ بے مقصد طوالت میں کہیں بھی جاتا ہوا نظر نہیں آتا۔ پورے ناول میں کوئی واقعہ فاضل نظر نہیں آتا بلکہ کہانی کی بُنت کا لازمی جُز معلوم ہوتا ہے۔ وہ ہر واقعہ کی جزئیات کو بڑی تفصیل سے بیان کرتا ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اس واقعہ کے رونما ہونے کے وقت وہ خود وہاں موجود تھا اور وہ جو کچھ لکھ رہا ہے وہ اس نے اپنی آنکھوںسے دیکھا ہے مثلاً گھوڑوں کی ریس کا منظر اس نے بڑی باریک اور نفیس تفصیلات کے ساتھ بیان کیا ہے جس سے ٹولسٹوئی کے گہرے مشاہدے کا پتا چلتا ہے اور یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس مشاہدے کو لفظوں میں بیان کرنے پر اسے کیسی بے مثال مہارت حاصل ہے۔ گھوڑوں کی اس ریس کو اس نے علامتی معنویت میں استعمال کیا ہے کہ اس میں پورے ناول کی روح سما گئی ہے۔ اس کے علاوہ بھی جگہ جگہ علامتوں کا بڑا خوب صورت استعمال کیا گیا ہے۔ خاص طور سے وہ خواب جو ناول میں بیان کیے گئے ہیں۔ وہ بھی علامتی معنویت کے طور پر استعمال ہوئے ہیں مثلاً اینا بار بار ایک خواب دیکھتی ہے کہ نچلے طبقے کا ’’ایک گندا سا شخص جھک کر ہتھوڑی سے لوہے کی کسی چیز پر وار کر رہاہے۔‘‘ ۱۶؎ اس خواب کی معنویت کو Vladimir Nobokov نے بہت سراہا ہے۔’’ آننا کے خواب میں وہ گندا سا شخص جو کچھ لوہے کے ساتھ کر رہا ہے، یہ وہی ہے جو’’ آنناکی گناہ آلود زندگی نے اس کی روح کے ساتھ کیا ہے اور اسے برباد کر دیا ہے۔‘‘ (۱۷)
ٹولسٹوئی نے تشبیہات کا بھی بڑا خوب صورت استعمال کیا ہے۔ مثال کے طور پر آنناکاریینیا کی زبان سے ٹولسٹوئی نے جس تشبیہ کی وساطت سے اس کی داخلی کیفیت کو بیان کروایاہے۔ اس سے بہتر انداز ممکن نہیں تھا۔
’’میں ساز کے حدسے زیادہ تنے ہوئے تار کی طرح ہوں جو ٹوٹ کر رہے گا۔‘‘ (۱۸)
آخر میں ناول کی تیکنیک کے حوالے سے اس بات کا ذکر ضروری ہے کہ اگرچہ اینا کیرینینااور لیون کے اردگرد پھیلے ہوئے واقعات کے حوالے سے ناول کا پلاٹ دو حصوں میں منقسم نظر آتا ہے، لیکن گہرائی میں جا کر دیکھیں تو ان میں ایک ربط موجود ہے اور وہ اس طرح کہ ٹولسٹوئی نے اینا کیرینیناکو روحانی گراوٹ اور آخرکار موت کی وادی میں جاتے ہوئے دکھایا ہے جب کہ دوسری طرف لیون ہمیں روحانی بلندی پر جاتا نظر آتا ہے۔
لیوٹولسٹوئی کا ناول ’’آنناکارینینا ‘‘ اپنی کہانی، کرداروںاور اسلوب نگارش کے نقطۂ نظر سے انیسویں صدی کاہی نہیںبلکہ بیسویں صدی اور اب اکیسویں صدی کے آغاز میں بھی فن کی بلندیوںپر نظر آتا ہے۔ عالمی کلاسیکی ادب میں اسے جو مقام حاصل ہے وہ بہت کم ناولوں کو نصیب ہوا۔
ناول نگاری کی تاریخ میں اس ناول کو عظیم ترین قرار دینا بے جانہ ہوگا۔ آنناکارینینا، ٹولسٹوئی کی ماسکو اور سینٹ پیٹرز برگ کے موازنے میں محبت اور ناجائز تعلقات کی قدیم داستان ہے۔ ایک زرخیز اور پیچیدہ شاہکار ناول جو کہ آننا، ایک خوب صورت شادی شدہ عورت اور کائونٹ ورونسکی، ایک دولت مند فوجی افسر کے درمیان محبت کے سلسلے کے تباہ کن راستے کا نقشہ کھینچتا ہے۔ ٹولسٹوئی اس کے ساتھ ہی دوسرے درجن بھر کرداروں کی زندگیوں کو بھی باریک بینی سے بُنتا ہے اور ایسا کرتے ہوئے وہ انیسویں صدی کے اواخر کے روسی معاشرے کو دم بہ خود کر دینے والی گُلکاری کی طرف متوجہ کرتا ہے۔
اُنیسویں صدی کے روس میں اُبھرنے والا یہ شاہکار ناول توقعات سے وابستہ رہنے کے دبائو، ایک معاف نہ کرنے والے معاشرے کے حصے اور افراد کے اپنی تقدیر کے پیچھے ذاتی خواہشات کو بیان کرتا ہے۔ ایک مطالعہ جو قاری کو دیے گئے سبق کو نہ بھولنے پر مجبور کرتا ہے۔ یہ دوسرے لوگوں کے تجربات اور غلطیوں سے سیکھنے کو حقیقی معنی دیتا ہے۔ ایک رہنما جو کہ اِن خواہشات کی وجہ سے پیدا ہونے والے نتائج کو ایک مثال کے ذریعے دکھاتے ہوئے رہنمائی کی طرف لے جاتا ہے۔
انیسویں صدی کی تیسری دہائی تک روس سے باہر اِس ضمن میں کوئی متضاد رائے نہیں تھی کہ روس کے عظیم ترین قلم کار…ٹولسٹوئی نے روسی ادب میں اس طرح سے غلبہ حاصل کیا جیسا کہ Goetheکی وفات کے بعد سے دنیا کی نظر میں بین الاقوامی ادب کو کسی نے متاثر کیا تھا۔
مغربی باشندوں کے اذہان کو جس نے سب سے زیادہ متاثر کیا اور Dostoyevskyکے متبادل کے طور پر جو غیر معمولی شہرت اور ادب کی دنیا میں معروف ہونے والا ادیب تھا تو وہ غیر معمولی تخلیقی قوت کا مالک ٹولسٹوئی تھا۔ ٹولسٹوئی فکشن کے افق پر ایک درخشاں ستارے کی طرح نمودار ہوا ۔ اگر ہم ٹولسٹوئی کی ادبی زندگی کے دوامی ہونے کی بات کریں تو اس پر کوئی سوالیہ نشان نہیں لگایا جا سکتا۔ یہ امر روزِ روشن کی طرح عیاں ہے کہ ٹولسٹوئی فکشن کی دنیا میں دوامی زندگی رکھنے والا ادیب ہے۔
حقیقت میں ٹولسٹوئی کی اثر پذیری میں اتار چڑھائو تو ہو سکتا ہے: جیسا کہ آج ہم دیکھتے ہیں۔ اس چیز سے انکار بہت مشکل ہے کہ وہ ایک باکمال ادیب تھا اور ایک عظیم انسان بھی، لیکن مجموعی اعتبار سے ٹولسٹوئی کا ستارا کبھی زوال پذیر نہیں ہوسکتا، کہ وہ ایک عظیم ترین انسان تھا( نہ صرف عظیم لوگوں میں‘ بلکہ شاید عظیم تر لوگوں میں بھی ایک عظیم ترین انسان تھا۔ ) ٹولسٹوئی نے ادب عالیہ میں غیر معمولی کارہائے نمایاں انجام دیے۔ اسی لیے اُسے دوام حاصل رہے گا۔ اس نے اپنی تخیلاتی قوت سے اپنے ناول کو روشن کیا۔ (ٹولسٹوئی Freud کے بعد دنیائے ادب پر نمودار ہوا۔ آرٹسٹ اور سائنس دان میں اگر موازنہ کریں تو آرٹسٹ زیادہ تخیلاتی ہوتا ہے جب کہ سائنس دان تجربی علم پر تیقن رکھتا ہے۔ )
’’اس ناول میں زندگی کی وہ وسعت نہیں دکھائی گئی ہے جو کہ ’’جنگ اور صلح‘‘ کی امتیازی خصوصیت ہے، اس کا موضوع چند افراد کی زندگیاں ہیں، لیکن تالستایٔ کی نظر وہی ہے کہ جس نے ’’جنگ اور صلح‘‘ کو ناول نویسی کا کرشمہ بنا دیا اور میدان کے محدود ہو جانے سے روشنی جہاں پڑتی ہے تیز پڑتی ہے۔ اس ناول میں سیاست اور تاریخ سے بحث نہیں ہے، اخلاق سے ہے، مگر اس انداز سے کہ نہ تو انجام سے وہ بے تعلقی برتی گئی ہے جو رسم نے حقیقت نگار کے لیے لازمی بنا رکھی ہے اور نہ وہ ناصحانہ طریقہ اختیار کیا گیا ہے جو تالستایٔ کی بعد کی تصانیف میں ملتا ہے۔ کسی کی زندگی بگڑتے دکھائی گئی ہے، کسی کی بنتے، کسی کو طبیعت اور عادت نے ایسا سخت کردیا ہے کہ وہ نہ بگڑ سکتا ہے نہ بن سکتا ہے، کسی کی زندگی بس جینے میں ہے اور اسے اس کا احساس ہی نہیں کہ بگڑنا کیا ہے اور بننا کیا ہے، لیکن صورتیں، سیرتیں، جذبات کے پلٹے، واقعات، تقرمی بیں۔ سبھی کے بیان کرنے میں تالستایٔ نے کمال دکھایا ہے اور اس کا اخلاقی حسن کبھی اسے حشم پوشی یا حقیقت کو صاف صاف دکھانے سے پرہیز کرنے پر مجبور نہیں کرتا۔ آخری حصّہ باقی ناول کے مقابلے میں بے شک ذرا کم زور ہے، کیوں کہ اس وقت جب یہ لکھا گیا تالستایٔ پر ایک روحانی کیفیت طاری تھی جس نے اس کی طبیعت کو ناول نویسی سے ہٹا دیا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح سے یہ پاپ کٹے۔
![]()